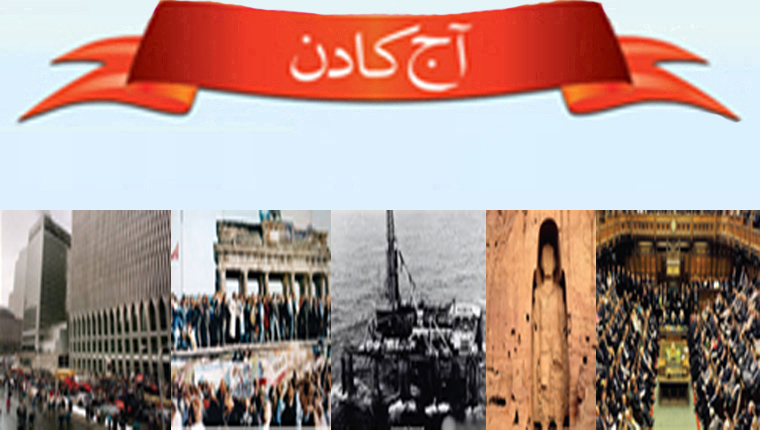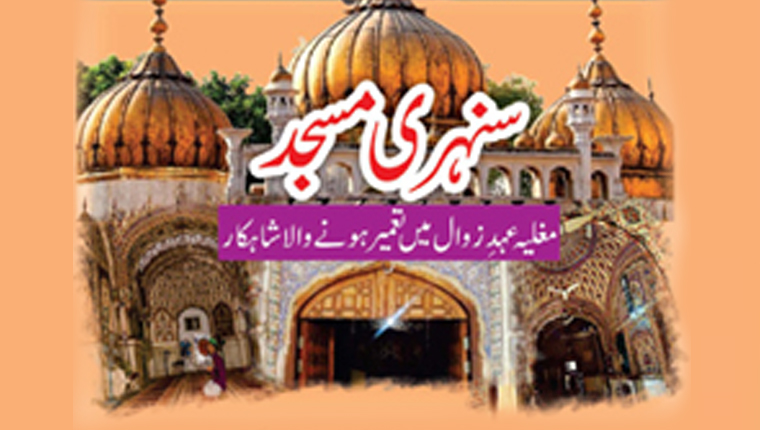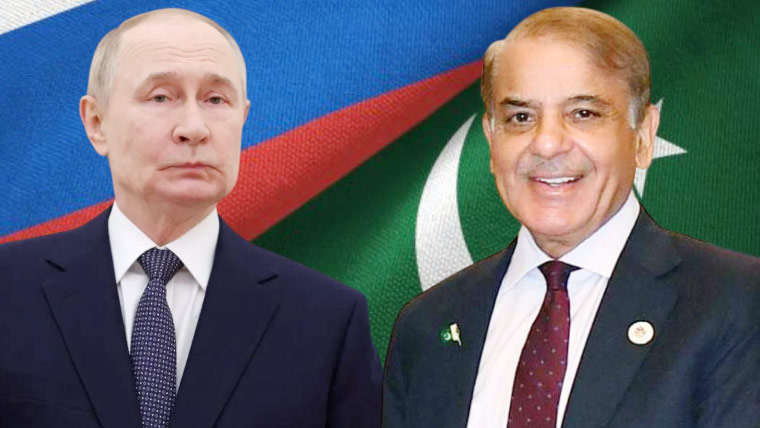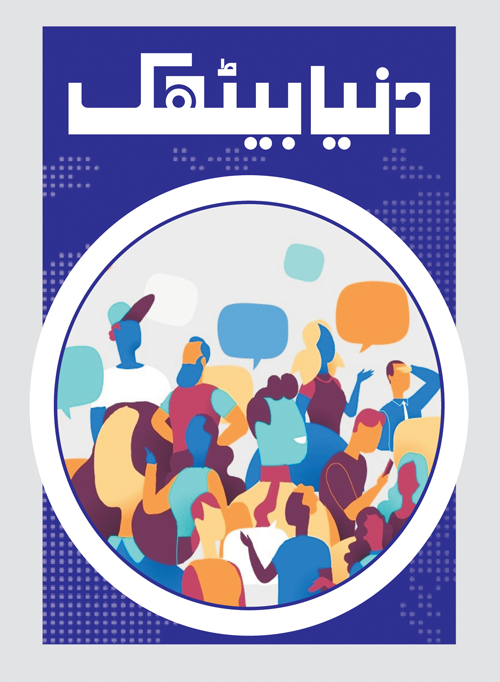ڈاونچی کوڈ کے مصنف ڈین براؤن کے تازہ ناول Inferno کا شہرہ
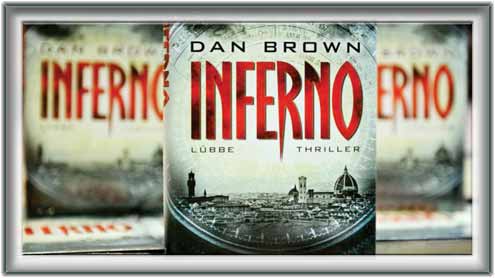
اسپیشل فیچر
امریکی ادیب ڈین براؤن کا لکھا ہوا تازہ ناول(انفیرنوInferno) آج کل جرمن جریدے ڈیئر اشپیگل کی تفریحی ادب کی بیسٹ سیلر فہرست میں سب سے اُوپر جا رہا ہے۔ اس میں اُنھوں نے عالمی آبادی میں ہونے والے خطرناک اضافے کو موضوع بنایا ہے۔اس ناول کی تشہیر کے سلسلے میں ڈین براؤن نے گزشتہ دنوں جرمنی بھی گئے ہوئے تھے، جہاں اُنھوں نے کولون میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں اپنے اس ناول میں سے اقتباسات بھی پڑھ کر سنائے۔ یاد رہے کہ ڈین براؤن کا شمار دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ادیبوں میں ہوتا ہے۔ ڈین براؤن کا تازہ ناولInferno مئی کے وسط میں منظر عام پر آیا تھا جب کہ وہ مئی کے اواخر میں کولون گئے۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ڈین براؤن کسی عوامی اجتماع میں شریک ہوں۔ کولون میں منعقدہ تقریب جرمنی بھر میں واحد تقریب تھی، جس میں وہ شریک ہوئے۔اس موقع پر اُنھوں نے بتایا کہ آج کل ہر روز عالمی آبادی میں دو لاکھ انسانوں کا اضافہ ہو رہا ہے اور یہ کہ اُن کی نظر میں آج کل دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک مسئلہ آبادی میں تیزی سے ہوتا ہوا یہی اضافہ ہے۔ ڈین براؤن نے اپنے اس تازہ سنسنی خیز ناول میں اسی موضوع پر قلم اُ ٹھایا ہے۔اپنے اس ناول میں ڈین براؤن نے اس عالمی مسئلے کو دانتے کی ’ڈیوائن کامیڈی‘ میں بیان کیے گئے دوزخ کے منظر نامے سے مربوط کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ’’عالمی آبادی میں حد سے زیادہ اضافے کے بارے میں پڑھتے پڑھتے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ دانتے نے دوزخ کا جو نقشہ کھینچا ہے، وہ ہمارے مستقبل سے کافی ملتا جلتا ہے چناں چہ مجھے ایک ایسا ولن تخلیق کرنے کا خیال آیا، جو دانتے کے تصورات کو محض ایک کہانی کے طور پر نہیں بل کہ ایک پیش گوئی کے طور پر لیتا ہے‘‘۔ ناولInferno کے واقعات زیادہ تر اطالوی شہر فلورینس میں پیش آتے ہیں، جو کہ دانتے کا شہر رہا۔ اسی شہر میں ڈین براؤن اپنے اس ناول کے سلسلے میں تحقیق بھی کرتے رہے ہیں۔ڈین براؤن خود کو ایک محتاط اور ہجوم سے گریزاں شخص قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اُن کی کتابوں کا اولین مقصد قاری کو تفریح فراہم کرنا ہوتا ہے، لیکن اُن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ناولوں کے لیے کسی اہم موضوع کا انتخاب کریں۔ ڈین براؤن کے مطابق ’’جب لوگ ناولوں میں بیان کیے گئے مقامات اور فنی شاہکاروں میں دلچسپی لیتے ہیں ،تو اُنھیں اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے‘‘۔ امریکی ادیب ڈین براؤن کا کہنا ہے ’’اُن کی کتابوں کو ملنے والی بے پناہ کامیابی سے اُن کی زندگی میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے، ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ اُنھوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر شہر سے دُور دیہی علاقے میں ایک خوبصورت گھر ضرور بنایا ہے‘‘۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب ’’ ڈا ونچی کوڈ‘‘ کی اشاعت کے برسوں بعد بھی وہ اپنی پرانی کار ہی استعمال کر رہے ہیں: ’’مَیں اور میری بیوی، ہم دو ایسے انسان ہیں، جنھیں آرٹ اور فن تعمیر سے دلچسپی ہے، ہمیں کاروں، زیورات اور اس طرح کی چیزوں کا کوئی شوق نہیں‘‘۔واضح رہے کہ ڈین براؤن کی کتاب ’’ ڈا ونچی کوڈ‘‘ نے پوری دنیا میں زبردست شہرت حاصل کی ہے، اس ناول پر فلم بھی بنائی گئی ہے۔ کولون میں اپنے تازہ ناول کے حوالے سے ڈین براؤن کا کہنا تھا: ’’اس کتاب کو تحریر کرنے میں تین سال سے کچھ زیادہ عرصہ لگا ہے تاہم ’ ڈاونچی کوڈ‘ کی کامیابی کے بعد مجھے ایسے بہت سے خفیہ مقامات کا پتا چلا ہے، جن کا مجھے پہلے علم نہیں تھا‘‘۔اپنی کتابوں میں ڈین براؤن نے جس انداز سے مسیحیت کو پیش کیا ہے، اُس پر ویٹی کن کے نمایندے اُن سے کافی ناراض ہیں۔ خود براؤن ہرگز نہیں سمجھتے کہ مذہب اور سائنس کے درمیان کوئی تضاد پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ اُنھوں نے الجبرا یا طبیعیات پر غور کیا ہے، اتنا زیادہ اُن پر مذہبی جہات کے دَر وَا ہوتے چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ’’ آج کل اُنھیں اس بات کا یقین ہے کہ سائنس اور مذہب در حقیقت دو مختلف زبانیں ہیں، جو ایک ہی کہانی بیان کرتی ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دشمن نہیں‘‘۔ڈین براؤن 1964ء میں امریکی ریاست نیو ہیمپشائر میں پیدا ہوئے۔ اُن کے والد الجبرا کے پروفیسر تھے جب کہ والدہ موسیقار تھیں۔ ہنگامہ خیز ناولوں سے شہرت پانے سے پہلے اُنھوں نے انگریزی زبان کے اُستاد کے طور پر کام کیا۔ اپنے سنسنی خیزی، سائنسی اور تاریخی موضوعات اور سازشی نظریات سے عبارت ناولوں کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں گزشتہ چند عشروں کے کامیاب ترین ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔٭…٭…٭